سوال 1: پیشہ ورانہ تربیت کی تعریف کریں اور دیہی ترقی میں اس کی اہمیت اور ضرورت بیان کریں۔
جواب پیشہ ورانہ تربیت:
انٹیگریشن میں ایک بات جو سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے وہ مختلف محکموں میں کام کرنے والے ماہرین کی الگ الگ پیشہ ورانہ تربیت اور مخصوص فنی تعلیم کا حامل ہونا ہے۔ جہاں اس مخصوص فی تعلیم وتربیت سے بعض اوقات انٹیگریشن مشکل ہو جاتا ہے وہاں بذات خود مخصوص فی تعلیم و تر بیت کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ سپیشلائزیشن سے مختلف مہارتیں اعلیٰ ترین حد تک فروغ پاتی ہیں اور ان مہارتوں کو حاصل کرنے کیلئے ایک لمبا عرصہ اور جد و جہد چاہیے ہوتی ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر اور ایک اچھا مگر انوسٹ بنے کیلئے ایک طویل عرصہ اور ایک مخصو قامی وتربیتی پروگرام درکار ہوا ہے۔ خصوصی ماہرانہ تعلیم کی امیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ عملی زندگی میں ان مہارتوں کو ایک سوئی سے جوں جوں استعمال کیا جاتا ہے توں تو یہ زیادہ پکھرتی چلی جاتی ہیں۔ سپشلائز یشن کیلئے یہ بھی ؟ ضروری ہے کہ مختلف نوعیت کے کاموں کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ رکھا جائے۔ کیونکہ تربیت اور تجربہ صرف اسی صورت میں سود مند ثابت ہوتا ہے جب ایک شخص کو طرح طرح کے کام نہیں کرنے پڑتے اور اسے ایک ہی طرح کا کام سونپا جائے۔ مختلف خصوصی ماہرین کے کاموںکو یکجا کیا جائے خصوصا جن کا شعبہ ایک3 ہی ہو ۔ جیسا کہ ایک زچہ بچہ کے کام کی ماہر ڈاکٹر اور ایک انیس تھاٹ کے کاموں کو تو اس لئے آسانی سے اکٹھا کیا جاسکتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر ان کا شعبہ صحت ے تعلق ہے لیکن ایک ماہرڈاکٹر اورایک اینیستھٹ کے کاموں کومشکل ہی سے ایک دوسر ے ساتھ لایا جاسکتاہے کیونکہ یا توان کی تعلیم الگ الگ ہے اور دوسرے ان کی مہارتیں بھی جدا جدا ہیں ۔
سوال 2: معاشرتی تحقیق سے کیا مراد ہے؟ معاشرتی تحقیق کے مراحل کو تفصیل سے بیان کریں۔
جواب: تحقیق کے مراحل
کسی بھی تحقیق کا آغاز دراصل کسی مسئلہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طر پراس مسئلہ کودیکھئے: ضلع فیصل آبادی کچھ تحصیلوں میں اس کے باوجود کہ محکمے کے کارکنوں نے کاشتکاروں کوسیم وتھور کے مسئلے سے نمٹنے کے طریقوں سے بخوبی آگاہ کیا، بہت کم کا شتکاران پر عمل کر پائے ۔ آئیے دیکھیں کہ آپ اس مسئلے کے حل کیلئے مندرجہ ذیل اقدامات میں سے کن کی سفارش کریں گے :
1 کا شتکاروں کوان طریقوں پر مل کرانے کیلئے مختلف نوعیت کی ترغیبات دینی چاہئیں ( انعام واکرام وغیرہ)۔
2 حکومت کا شتکاروں کو مجبور کرے کہ وہ وسیم وتھور کے مسئلہ سے نمٹنے کیلئے یہ طریقے لازمی طور پر اپنائیں۔ ( مختلف قوانین کا حوالہ
3 کاشتکاروں کو ان طریقوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ مہارتیں بھی سکھائی جائیں۔
4 کا شتکاروں کو ان طریقوں پر عمل درآمد سے متعلق مختلف ذرائع بھی فراہم کئے جائیں۔
5 کا شتکاروں کو ان طریقوں کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے کہ سیم و تھور کا مسئلہ حل ہونے سے انہیں کیوں کر فائدہ پہنچے گا۔
آپ نے یقیناً ان اقدامات میں سے کچھ کو مؤثر سمجھتے ہوئے ان کی نشاندہی کی ہوگی اور ویسے بھی تو یہ گنتی کے چند اقدامات شاید ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اقدامات آپ کے ذہن میں آئے ہوں لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی یہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ کی تمام کی تمام سفارشات پر عمل درآمد کے باوجود یہ صحیح نہ ہو سکی بلکہ یوں سمجھئے کہ پہلے تو اوپر بیان کردہ اقدامات کی اس فہرست کو عمل کیا گیا پھر ہر اقدام کو باری باری آزمانے کے باوجود سیم وتھور پر کنٹرول کرنے کےطریقوں پر کاشتکاروں سے عمل نہ کروایا جا سکا۔ کیا آپ سوچ کر بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟
آئیے آپ کو چندان صورتوں کے بارے میں بتائیں جہاں یہ سب کے سب اقدامات بالکل بے کار ثابت ہو سکتے ہیں :
1 ہوسکتا ہے ضلع فیصل آباد کی ان تحصیلوں میں سیم و تھور کا مسئلہ سرے سے موجود ہی نہ ہو۔
2 ہوسکتا ہے محکمے کے کارکن کا شتکاروں کو سیم و تھور سے نمٹنے کے طریقوں سے آگاہ ہی نہ کر پائے ہوں۔
3 ہوسکتا ہے جن کا شتکاروں کوان طریقوں کی تعلیم دی گئی وہ ہوں جنہیں یہ مسئلہ در پیش ہی نہ تھا۔
4 ہوسکتا ہے کاشتکاروں کے پاس سیم وتھور کے مسئلہ سے نمٹنے کیلئے کچھ اورمتبادل بہتر طریقے موجود ہوں ۔
5 ہوسکتا ہے کا شتکار ان طریقوں کو جاننے کے بعد واقعی عمل کر پائے ہوں لیکن ہم کو ان کا علم نہ ہو سکا ہو۔
6 ہوسکتا ہے کارکن صرف ان کا شتکاروں تک رسائی حاصل کر سکے ہوں جو پہلے ہی سے زیادہ بہتر طریقوں پر عمل کر رہے ہوں وغیرہ وغیرہ۔
ظاہر ہے ان صورتوں میں پہلے بیان کردہ اقدامات بالکل بے کار ثابت ہوں گے۔ آیئے دیکھیں کہ ایسی صورتیں کیوں کر پیدا ہوسکتی ہیں؟ یہ وہ غیر تصدیق شدہ امور نے جنہیں ہم نےاپنے ذہنوں میں آباد رکھاتھالیکں حقیقتایہ اپناوجود نہیں رکھتے تھے ان غیرتصدیق شده امورکی زبان سے ہم مفروضے کہتے ہیں ۔ مثلاً ان لوگوں کے ذہنوں میں جنہوں نے اسے ایک مسئلہ تصور کیا یہ سب مفروضے تھے کہ:
1 ضلع فیصل آبادی ان تحصیلوںمیں سیم وتھور کا مسئلہ بہت زیادہ تھا۔
2 محکمے کے کارندوں نے کاشتکاروں کو سیم و تھور کے مسئلے سے نمٹنے کے مختلف طریقوں سے بخوبی آگاہ کیا
3 کاشتکار یہ سب کچھ جانے کے باوجودان طریقوں پرعمل نہ کر پائے۔
4 سیم و تھور کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے یہ طریقے نہایت موثر تھے۔
5 سیم و تھور کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے کافی تھا کہ کاشتکار ان طریقوں کے بارے میں جان جائیں وغیرہ وغیرہ۔
سوال 3 معاشرتی اور غیر معاشرتی حقائق کے درمیان فرق واضح کریں۔ معاشرتی حقائق کو پرکھنےکیلئے بنیادی اصول بیان کریں۔
جواب: معاشرتی اور غیر معاشرتی حقائق:
علم کا مطلب ہے جاننا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہے تو دراصل ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ وہ شخص ہے بہت کی حقیقوں کا علم ہوہم اسے ایک عالم کہتے ہیں لیکن بہت ی با تیں جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوتی ہیں یا دوسرے معنوں میں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جن باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے ضروری نہیں کہ حقیقت ہوں ۔ ہاں ایک بات ہم نے ضرور محسوس کی کہ بعض باتیں کسی حد تک ناگزیر ہوتی ہیں اور انہیں کوئی بھی رد ہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں حقائق تصور کرتے ہیں مثال :
ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اگر ہم اسے اوپر کی طرف پھینکیں تو واپس زمین پر گرتی ہے۔
ہائیڈ روجن گیس کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ مل کر پانی بنتا ہے۔
ایک زندہ انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔
دنیا گول ہے وغیرہ وغیرہ۔
یہ سب غیر معاشرتی حقیقتیں ہیں کیونکہ جب ہم اپنے ذہن میں اس شخص کا ایک فرضی تصور باندھتے ہیں جو اس ساری زمین پر تنہا زندگی بسر کر رہا تھا اورجس نے اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کو نہ تو بھی دیکھا اور دہی بھی ساتھ تو اس وقت بھی ہر وہ چیز جو اپناو رکھتی تھی اگر اوپر کی طرف پھینکی جاتی تو واپس زمین پر آ گرتی ۔ اس وقت بھی پانی ہائیڈ روجن گیس کے دو حصوں اور آکسیجن کے ایک حصے ہی سے مل کر بنتا تھا۔ اس وقت بھی اس انسان کے جسم میں خون گردش کرتا تھا . جس طرح یہ آج ہمارے جسموں میں ۔ اس وقت بھی دنیا گول تھی جیسے کہ یہ آج ہے۔ ان تصورات کیلئے ایک سے زیادہ افراد کی موجودگی اور ان کے درمیان باہمی را تعلق کا ہونا لازمی نہیں۔ انہیں ہم حقیقتیں اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آئے اب دیکھیں کہ ان حقیقتوں کو کن صورتوں میں یعنی کس طرح جھٹلایا جا سکتا ہے؟ پہلے کشش ثقل ہی کا اصول لیجئے ۔ ہر وہ چیز جو اپنا وزن رکھتی ہے اگر و اوپر کی طرف پھینکی جائے تو واپس زمین پر گرتی ہے۔ جو بھی اے بھلانا چاہے اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ اسکا تجربہ کر کے دکھے یعنی کسی وزنی چیز کو لے اور پھر اسے اوپر کی طرف پھینک کر دیکھے۔ اگر یہ چیز بجائے اس کے کہ واپس زمین پر آ گرے ہوا ہی میں لٹک جائے تو اس شخص کو پہلے تو یہ شک گزرے گا کہ بھئی یہ بات تو غلط نکلی کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اگر یہ چیز ہوا میں معلق ہونے کی بجائے آسمان کی طرف سیدھی کھنچتی چلی جائے تو اسے بجائے اس کے کہ یہ شک گزرے کہ یہ بات غلط ہے اس کے دل میں اس کے بالکل غلط ہونے کا اٹک گزرے گا۔ اب اپنے اس شک کوس قدر یقین میں بدلنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے تو وہ خود اس تجربے کو بار بارہ ہرائے۔ اگر بار بار ایسا کرنے سے یہی نتیجہ نکے تو ی سوچتے ہوئے کہ کہیں یہ چیز تو ایسی نہیں جسے اوپر کی طرف پھینکا جائے تو یہ اپنے آپ آسمان کی طرف کھنچتی چلی جائے‘یاکہیں یہ جگہ اور مقام ہی تو ایسا نہیں یا ہیں اس کو ایک طرف پینے کا طریقہ تو یہ نہیں اس طریقے سے بھی جوبھی چیزاوپر پھینکی جا ئےتو وہ واپس لوٹےیا کہیں اج کادن وقت یا جولمحہ ہی تو ایسا نہیں کہ صرف اس روز اس وقت یا اس لیے بھی ایسا ہو پایا یا کہیں میں (یعنی وہ شخص ) خود ہی تو ایسا نہیں کہ جس چیز کواو پر پھینکوں تو اوپر چلی جائے لیکن جب کوئی دوسرا پھینکے تو ایسانہ ہو۔“
مختلف قسم کی چیزوں کو
مختلف جگہوں یا مقامات پر
مختلف طریقوں سے
مختلف دنوں اوقات یا لمحوں میں
اوپر کی طرف پھینک کر دیکھے بلکہ اوروں سے بھی کہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ فرض کیجئے اگر ہر بار ہی نتیجہ نکلے کہ اوپر پھینکی ہوئی چیز یا تو ہوا میں رہ جائے یا اوپر آسان ہی کی طرف کھنچی چلی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ کشش ثقل کا اصول ایک حقیقت نہیں۔“ مگر ہم جانتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور اسی لئے کشش ثقل کا اصول ایک حقیقت ہے ۔ کشش ثقل کا اصول اس لئے ایک حقیقت ہے کیونکہ مختلف چیزوں کو جب مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے مختلف وقتوں میں بار بار مختلف لوگوں نے آسمان کی طرف پھینکا تو وہ ہر بارز مین کی طرف لوٹ آئیں۔ دراصل یہ سب کچھ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان ایک بڑا واضح تعلق پرکھ سکیں۔ ان میں سے ایک تو ہے وجہ اور دوسری ہے اس وجہ کا نتیجہ ۔ فرض کیجئے اگر کسی چیز کو بار بار آسمان کی جانب پھینکا جائے تو وہ او پر ہی کھنچتی چلی جائے (مثال کے طور پر چاند کی جانب جانے والا راکٹ ) لیکن جب مختلف قسم کی اور بہت سی چیزوں کو او پر پھینکیں تو وہ واپس زمین کی جانب لوٹ آئیں تو ہم کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ ظاہر ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تو اس چیز کی اپنی کوئی خصوصیت ہے کہ وہ بجائے زمین کے آسمان کی طرف کھنچتی چلی گئی تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں ہم نے جن دو کے درمیان ایک واضح تعلق پر کھا وہ وہیں: اس چیز کی اپنی کوئی خصوصیت اور اس چیز کا آسمان کی طرف کھچاؤ کا عمل۔
اس طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک چیز کی خاص مقام پر تو آسان کی جانب کھنچی چلی جائے لیکن باقی سب مقامات پر ایسا نہ ہوتو یہاں اس مقام کی اپنی 3 کوئی خصوصیت اس چیز کے آسان کی جان کھچاؤ کی وجہ بنے گی اور اگرکی خاص طریقے سےتو ایک چیز آسان کی طرف کھنچتی چلی جائے لیکن جب دوسرے " طریقوں سے پھینکی جائے تو ایسا نہ ہوتو اس طریقے کی اپنی کوئی خصوصی وجہ ہوگی اور اگرکی خاص روز تو ایسا ہوا ہولیکن دوسرے وقتوں میں بھی ایسا نہ ہوسکا توہم 3 بآسانی کہ سکتے ہیں کہ وہ خاص حصہ یاوقت اس چیز کے آسان کی جانب کھچاؤ کا سب بنتا ہے اوراسی طرح اگر کسی ایک شخص کے ہاتھوں تو ایک چیز او پر چلی جائے ما لیکن جب دوسرے پھینکیں تو ایسانہ ہو پائے تو ہم کہیں گے کہ اس شخص کی کوئی اپنی خوبی اس شے کے آسمان کی جانب کھچاؤ کی ذمہ دار ہے لیکن جیسا کہ ہم جانتے " ہیں مختلف وقتوں میں جب مختلف قسم کی چیزوں کومختلف مقامات پر بار بار مختلف لوگوں نے آسمان کی جانب پھینکا تو وہ آسمان کی جانب کھنچنے کی بجائے ہر بار واپس ریار وایس ہ زمین کی جانب لوٹ آئیں۔ اس لئے کشش ثقل وجہ ہے چیزوں کے زمین کی طرف کھچاؤ کی۔ کش ثقل کا اصول ایک غیر معاشرتی اصول ہے۔اسے ہم بآسانی پرکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جن چیزوں کےمشاہد ے کی ضرورت پیش آئی وہ ایسی تھیں کہ ان کا بآسانی مشاہدہ کیا جاسکتا تھا۔ مثال کے طور پر ہروہ چیز جسے ہم آسمان کی طرف پھینکتے رہے اپنا ایک حقیقی وجود رکھتی تھی اسکا وزن تھا اس کی کوئی نہ کوئی شکل تھی۔ اسے ہم چھو سکتے تھے اسکی لمبائی چوڑا ئی موٹائی ناپ سکتے تھے وغیرہ غیرہ) پھر ہم اسے اوپر آسمان کی جانب جاتے اور پھر واپس زمین کی طرف لوٹتے بھی دیکھ سکتے تھے اور اگر تجربے میں اسکی ضرورت پیش آتی کہ کہ ہم ییہ بھی دیکھیں کہ چیز کتنی بلندی سےواپس لوٹی تو اس بلندی کاصحیح شما ربھی ممکن تھا جس رفتار سے یہ چیز واپس لوٹی اگر ہم چاہتے تو اس کا بھی صبح تعین کر سکتے تھے۔ پھر یہ جانے کیلئے کہ کیا یہ اس چیز کی اپنی کوئی خصوصیت تو نہیں ہم نے جن بہت سی مختلف چیزوں کواوپر کی جانب چھینا ان کا چناؤ بھی بڑا آسان تھا۔ بس ہم نے بآسانی ایسی چیزوں کو چنا جنکے وزن مختلف تھے جن کی شکلیں مخلف تھیں یہ مخلف و حجم رکھتی تھیں، ان کی لمبائی چوڑائی مختلف تھی ۔ ان تمام خصوصیات کو ہم ہندسوں میں ماپ سکتے پھر ہوتے ہوئے کہ یہ مقامی والی نہیں ہمارے لئے کا مختلف مقامات کاتعین کرنا بھی بڑا آسان تھا ہم نہ صرف ایک جگہ کا دوسری جگہ سے جتنا فاصلہ تھا اس سے مقامات کا چناؤ سطح سمندرسے کسی مقام کی بلندی دونوں 2 مقامات کرنا ہی برا نام صرف جگا برسے الایا اسے مقامات میں دونوں ہندسوں میں پورا پورا ماپا جا سکتا ہے اور پھر ہمارے لئے صرف ارد گرد کے طبعی ماحول ہی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بڑا آسان تھا کہ ایک مقام دوسرے مقام سے مختلف ہے۔ پھر یہ جانے کیلئے اگر ہر شخص کا چناؤ بھی ایک مشکل کام نہ تھا اس طرح مختلف اوقات اور اشیا کو او پر پھینکنے کے مختلف طریقوں کا چناؤ بھی اتنا مشکل کام نہ تھا۔ یہاں تک کہ زمین کی کش بظاہر دکھائی نہیں دیتی اس کا بھی سی صحیح اندازہ ہندوں میں لگایا جاسکتا ہے۔ جس رفتار سے ایک مقررہ وزن کی چیز ایک چیز ایک مقررہ بلندی سے نیچے گرتی ہے۔ اسی سے زمین کی کشش کو ماپا جاتا ہے۔ آئیے اب حقیقت کی اس تعریف کو مانتے ہوئے کہ ہر وہ چیز واقعہ یا عمل جس کی ایک کی گواہی ہر شخص ہر وقت ہر جگہ ہر طریقے سے جانچنے کے بعدیکساں نتائج حاصل کر کے دے ایک حقیقت کہلاتی ہے۔ ذیل میں درج دو معاشرتی حقائق کو پڑھیں : اپنی مدد آپ کے جذبے سے لوگوں میں مختلف قسم کے کام کاج کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔
کم بچے خوشحال گھرانہ
کسی بھی جگہ کسی بھی دور میں خواہ وہ کسی بھی معاشرے کے لوگ کیوں نہ ہوں اگر ان میں اپنی مدد آپ کا جذبہ موجود ہے اور اگر ہم میں سے ہر شخص ہرطریقے سے جانچنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ س اپنی مدد آپ کے جذبے کی وجہ سے ان لوگوں میں مختلف قسم کے کام کاج کرنے کی صلاحیتیں نتیجہ بڑھ گئی ہیں۔ تو ہم اسے ایک حقیقت کہیں گے۔ اسی طرح کم بچے خوشحال گھرانہ والی بات صرف اس وقت تک ایک حقیقت کہلائے گی جب ہم میں سے ہر شخص ہر طرح سے . جانچنے کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا میں ہر جگہ پر ہر دور میں ہر اس گھر جہاں بچوں کی تعداد کم ہو زیادہ خوشحالی ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہر کشش ثقل کے غیر معاشرتی اصول ہی کی طرح دو کے درمیان ایک واضح تعلق کی نشاندہی کر رہے ہیں جن میں سے ایک تو ہے وجہ اور دوسرا ہے اس کا نتیجہ۔ اپنی مدد آپ کا جذ بہ مختلف قسم کے کام کاج کی صلاحیتوں کے بڑھنے کی وجہ سے یا کم بچے خوشحال گھرانوں کا سبب بنتے ہیں۔کشش ثقل کا حساب ہندسوں میں لگایا جا تا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ فلاں مقام پر یہ 2013 ہے اور فلاں مقام پر 1. 309 لیکن ہم اس بات کا اتاصیح صحیح تعین نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص میں اپنی مدد آپ کا جذ بہ فلاں شخص سے کتنازیادہ یا کم ہے۔ ہم اسے اس طرح نہیں ماپ سکتے ۔ کشش ثقل کا تعین ہم اس رفتار سے کرتے ہیں جس سے کسی مقر وزن کی چیز، مثلا ایک پتھر زمین پر گرے۔ پتھر ایک بے جان شے ہے۔ اس کی نہ تو ہماری طرح کوئی سوچ ہے اوراس کےنہ تو ہماری طرح کوئی تصورات ہیں۔ یہ تو ہونہیں سکتاکہ ہم اسے اوپر پھیکیں تو اس خیال آئے کہ میں بجائے اس کے کہ : واپس زمین پر لوٹوں کیوں نہ اس جھیل کے کنارے جا گروں اور وہ یہ سوچ کر اپنا رخ خود ہی اس طرف کر لے یا یہ کہ میں اس آہستہ رفتار کی بجائے کیوں نہ تیزی ے گروں اور وہ ایسا کر پائے لیکن دوسری طرف جب ہم اپنی مد آپ کے جذبے کا تعین لوگوں پر چھ کرکرتے ہیں وہ پھروں کی طح کی کوئی ہے وہیں نہیں ۔ ان کی اپنی رائے اپنے خیالات اور احساسات ہوتے ہیں اور پھر ہم میں سے ہر ایک یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے بیچ جذبات اور خیالات کو دوسروں سے چھپائے رکھے مثلا اگر ہم کسی ے یہ سوال کریں کہ کیا آپ اپنی مرد آپ کرتے ہیں؟ تو شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جویہ کہے کہ نہیں۔“
پھر ایک ہی سائز کے ایک ہی حجم کے ایک ہی وزن کے کئی پتھر تو مل سکتے ہیں لیکن ہر انسان دوسرے انسان سے اس طرح بھی مختلف ہے کہ اس کے ذہن میں موجود تصورات اس کے خیالات اس کے تجربات اس کے احساسات سب کے سب دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں ظاہر ہے یہاں کوئی آپ کے سوال کا اپنے ذہن میں پہلے ہی سے موجود تصورات کی وجہ سے کچھ مطلب لےگا اور دوسرا کچھ اور مال ک طور پر زمین پرگرتے ہوئے پتھر کو دیکھ کر ہر شخص اس کا ایک ہی مطلب لے سکتا ہے ( شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو یہ کہے کہ یہ اوپر آسمان کی طرف جارہا ہے لیکن دوسری طرف چونکہ اپنی مدد آپ کے جذبے کے بارے میں سوال پو چھنے والا اور جواب دینے والا دونوں انسان میں ضروری نہیں کہ اول الذکراس جواب کا مطلب وہی سمجھ پائے جوموخر الذکر کے ذہن میں تھا۔ پھر بعض کے غیر معاشرتی حقیقوں کو پرکھنے کیلئے مثال کے طور پر جس طرح یہ حقیقت جانے کیلئے کہ پانی واقی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے ہم جس طرح پانی کو ہائیڈ روجن اور آکسیجن میں تو ڑ کر پھر دونوں کو مل کر دوبارہ پانی بنا لیتے ہیں ہم صلاحیتوں کو توڑ کر جذبے اور پھر جذبوں کو تو ڑ کر صلاحیتیں نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح کم بچوں اور خوشحال گھرانوں میں ایک واضح تعلق کو آسانی سے نہیں پر کھا جاسکتا۔ ہاں بچوں کی تعداد کا تعین تو ہندسوں میں ہو سکتا ہے لیکن کسی کے زیادہ بچے ہوتے ہوئے بھی اسے کم لگتے ہیں اور کوئی اپنے کم بچوں کو بھی زیادہ تصور کرتا ہے۔ پھر خوشحال گھرانہ ہم کسے کہتے ہیں؟ کیا وہ گھرانہ جس کی معاشی حالت بہتر ہو ایک خوشحال گھرانہ کہلائے گا یاوہ جس میں خوشیاں زیادہ ہوں چاہے وہ غریب گھرانہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر خوشیاں کوئی ایسی شے تو ہے نہیں کہ انہیں ایک گلاس میں ڈال کے ماپ لیں اور پھر کہیں کہ یہ گھرانہ اس گھرانے سے زیادہ خوشحال ہے اور پھر اکثر لوگ تو خوش نہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خوش ہیں اور بعض خوش ہوتے ہوئے بھی دکھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم خوشحال گھروں کا ایسا کوئی پیمانہ ڈھونڈ کر ہی لیں جس پر سب متفق ہوں تب بھی ضروری نہیں کہ یہ کم بچوں ہی کی وجہ سے ہو۔ ہو سکتا ہے اس گھرانے کی آمدنی مقابلتا بہتر ہو۔ اس گھر میں تعلیم زیادہ ہو۔ ان میں پرانی دشمنیاں نہ ہوں۔ ان کے پاس تفریح کیلئے زیادہ وقت ہو وغیرہ وغیرہ۔
اور پھر ہوسکتا ہے کہ ایک گھرانہ صرف بچوں کے کم ہونے کی وجہ سے ہی خوشحال نہ ہو بلکہ اس میں اس گھرانے کی معاشی حالت، گھر کے افراد کی تعلیم اسکی عمروں وغیرہ سب کا دخل ہو۔ ظاہر ہے اس صورت میں اس بات کا تعین کہ اس خوشحالی میں کس کا کتنا حصہ ہے اور کس کا کم ہے اور کس کا زیادہ اس مسئلہ کو مزید مشکل بنادیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ایسے کئی گھرانوں سے واقف ہے جہاں بچوں کی ویسے بھی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہی زیادہ خوشحال گھرانے ہوتے ہیں۔
سوال 4: دیہی ترقی کیلئے تعلیمی شعبوں میں مختلف ذرائع ابلاغ کا کردار تفصیلاً بیان کریں۔
جواب : ابلاغ کا کردار:
یقیناً ابلاغ معاشرہ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف مختلف لوگوں کے تصورات کو ہم آہنگ کرتے ہوئے ان کے مابین باہمی : 3 ربط اور تعلقات کو مضبوط کرتا ہے بلکہ یہ معاشرے میں تبدیلیاں لانے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی معاشرے میں اعصابی کھچاؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو کمیونی کیشن یا ابلاغ ہی کے ذریعے لوگ اس کھچاؤ کو کی قدر کم کر سکتے ہیں اس لئے جب کسی معاشرے میں کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں ایران کا میل خود کو تیز ہوجاتاہے اورلوگ گفت شنید کے ذریے ان خیالات کا اظہار ایک دوسرےسے کرتے ہیںاور یوں اعصابی کھاؤ کی یہ صورت کسی قدر نرم پڑ جاتی ہے۔
اعصابی کھچاؤ:
اعصابی کھچاؤ کی صورت کسی بھی معاشرے میں تب پیدا ہوتی ہے ۔ جب ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود زیادہ تر تصورات ان ؟ تصورات سے فوری طور پر ہم آہنگ نہ ہو جائیں جو ہمارے ذہنوں سے باہر موجود ہوتے ہیں مثال اگر ہم کسی طرح دیہی علاقوں میں یکسر انقلابی نوعیت کی غیر متوقع ہے بدیلیاں نے ہمیں اس کا زینتی ایک اعصابی کی ایک صورت میں ظاہر ہوگیا دوسرے عوں میں تبدیلیاں ہی ہو گی جن کا لوگ تصوربھی نہیں کرسکتے ہے تھے ۔ اس صورت میں ظاہر ہے لوگ گفت و شنید کے ذریعے اپنے ذہنوں سے باہر موجود تصورات سے کسی قدر منطبق ہوسکیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات معاشرے میں اس طرح تبدیلیاں لانے سے پہلے ان کیلئے لوگوں کو تیارکرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ ایسی کی صورتحال کا ایک عمومی ردعمل ہمارے کچھ اس طرح کے تاثرات سے ہوتا ہے اس کا تو سوچ بھی نہ سکتے تھے ۔ ا سے نہ تو ہمارا دل مانتا ہے اور نہ ہی ہمارا دماغ وغیرہ وغیرہ۔ باہمی گفت و شنید سے لاشعوری طور پر و “ صرف تسلی ہوتی ہے لوگ بہت سی جگہوں پر اسی طرح کے بھی م جیسے اور بہت حنان بلکہ اس سے میں کیا ہے کہ ہم اپنے کااس طرح ترتیب دیں کہ یہ ذہنوں کے باہر موجود حقیقی تصورات سے کسی قدر قریب ہوسکیں ۔ لوگوں کو جب ایسےمواقع فراہم نہیں کئے جاتے تو وہ ان اقدامات پر عملدرآمد کے وقت رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کیلئے ابلاغ کے دوسرے ذرائع مثل اخبارات ریڈیو اور ٹیلی ویژن بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن یہاں اس ہموارکر کے دوسرے مثلا وری و با کردارادا کرتے ہیں لیکن بات کا جاننا ضروری ہے کہ بہت سے تحقیقی مطالعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے خیالات ان کی رائے اور ان کے رویوں کو بدلنے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر چلائی جانے والی ہیں اپنے طور پر زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتیں اور اگران کے نتائج نکلتے بھی ہیںتو وہ محض اس بحث اور گفت و شنید کے ذریعے جولوگ ان پروگراموں کے ردعمل کے طور پر آپس میں کرتے ہیں۔ اس صورت میں جیسا کہ ظاہر ہے ضروری نہیں کہ نتائج وہی نکلیں جن کے حصول کیلئے اخبارات ریڈ یو یا ٹیلی ویژن پر یہ ہمیں چلائی گئیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات یہ نتائج بالکل الٹ رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ وہی باتیں سنتے اور دیکھتے ہیں جنہیں وہ سناد یکھنا چاہتے ہیں اسی لئے ابلاغ کے یہ دیگر ذرائع بعض کم مدتی مقاصد کو حاصل کرنے میں اتنے مؤثر ثابت نہیں ہوتے جتنا کہ شروع شروع میں ان کو سمجھا گیا تھا۔ بہت کی سٹڈیز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ خیالات اور رویوں کی تبدیلی کے سب سے اہم محرکات کسی شخص کے اپنے خاندان کے افراد دوست اور دیگر ساتھی ہوا کرتے ہیں۔
تحقیقی نتائج:
اس سلسلے میں تحقیق کے ذریعے جو نتائج سامنے آئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:
۔1 لوگ اپنے اہم فیصلوں میں ذرائع ابلاغ سے زیادہ اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کا اثر قبول کرتے ہیں۔
2۔ان میں وہ لوگ زیادہ اثر رکھتے ہیں جو کسی شخص کے قریبی ساتھی ہوں اور اسی معاشرتی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔
3۔خیالات اور رویوں کی تبدیلی میں تحقیقی نتائج بہت کم یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے سے بلند کی دوسرے معاشرتی طبقے کے افراد کو متاثر کر سکا ہو۔
4۔ اس طرح یہ بھی بہت کم ثابت ہوا ہے کہ نچلے معاشرتی طبقے کے افراد نے اوپر کے معاشرتی طبقوں سے زیادہ اثر لیا ہو۔ یہاں اس کا ذکر کرنا بے جانہ ہوگا کہ ہمارے ہاں اکثر چوہدریوں، ملکوں، سرداروں اور بڑے زمینداروں کے نچلے طبقے کے لوگوں کے خیالات اور رویوں میں تبدیلی لانے کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ے لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ہیں اور خیال میں حقیقی تبدیلی بہت کم آتی ہے گوکہ معاشرتی دباؤ کے تحت اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔
5۔ایسے لوگ جو عام طور پر ایک ی طرح کی رائے خیالات اور رویے رکھتے ہوں قریبی ساتھی اور ایک طبقے کے افراد ) اپنی گروہی رائے آسانی سے ہیں بدلنے چا ہے ذرائع ابلاغ کی مددسے اپیلیں کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہوں ۔
6۔ گاؤں کی سطح پر ضروری ہیں کہ ایک شخص کی رائے کو ہر حال میں دقیق تسلیم کیاجاتا ہو۔ وہ ہمارا تاثر اس سے مختلف رہاہے لیکن حقیقت میں یہاں تخصیص کار (Specialization) کا عصر انی حد تک موجود ہوتا ہے ایک آدمی ایک شعبےمیں اپنا اثرورسوخ رکھتاہےتو ضروری نہیں کہ اس کی رائے کوئی دوسرے شعبے میں اتنا ہی قبول کیا جاتا ہو۔
-7 کسی شخص کے رویوں اور خیالات کی تبدیلی کا انحصار اس کے ذہن میں پہلے سے موجود موافق تصورات پر ہے ۔ کسی خاص موضوع پر اگر کوئی شخص پہلے ہی ے نہیں رکھتا ہوتو اس شخص کے مقابلے میں نے اس سے پوری ہو یا قبول کرے گا۔
-8 رو برو ابلاغ چونکہ ذرائع ابلاغ میں سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ ہے اس لئے لوگوں کے رویوں میں تبدیلیاں لانے کیلئے گاؤں کی سطح پر ایسی سرگرمیاں بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہیں جن میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروپوں سے مل کر کام کیا گیا۔
9۔ یہ گروپ ان افراد پر مشتمل تھے جن کی معاشرتی اقدار ایک جیسی تھیں اور جو ایک ہی معاشی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔
10- گوکہ رو بر و ابلاغ سب سے موثر ذریعہ ہے لیکن خیالات کی ترسیل شروع شروع میں اتنی تیزی سے عمل میں نہیں آتی۔ لیکن اگر یہ سلسلہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو لوگوں کے رویوں اور خیالات میں بڑی اہم تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے برف کا ایک چھوٹا سا گیند بنا کر اسے برف پر لڑھکا دیا جائے تووہ لڑھکتے لڑ ھکتے بہت بڑا بن جائے۔
11- ذرائع ابلاغ کو جب ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ موثر طریقہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کی مختلف آمیزشوں ( ریڈیو کے ساتھ اشتہارات یا ریڈیو ٹیلی ویژن دونوں کا استعال و غیره) که روبرو ابلاغ کوفروغ دینے کیلئے استعمال کیا جائے تو خیالات کی ترسیل اور بڑی تبدیلی عمل میں آتی ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ رسمی و غیر رسمی گروہی بحثوں کا اہتمام اس سلسلے میں بہت کامیاب طریقہ رہا ہے۔
12- دیہات کی سطح پر مختلف ترقیاتی محکموں کے کارکنوں کا مختلف ہم خیال گروپوں کے ساتھ گروہی بحثوں میں ان لوگوں ہی کی طرح حصہ لینا اس سلسلے میں بڑا ضروری ہے۔
13- رویوں اور خیالات کی تبدیلی بڑی جگہوں کے مقابلے میں چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں زیادہ تیزی سے عمل میں آتی ہے۔
سوال 5 مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں:
(الف) عارضی اور مستقل منصوبے۔
جواب: عارضی منصوبے
بجٹ:
عارضی منصوبوں کی مثالیں مختلف قسم کے بحث پروگرام اور پرا جیکٹ ہیں۔ انہیں خاص مقاصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک عام بجٹ اس لحاظ سے نہ ایک بلکہ دورے کے اخراجات پابندھی کردیا ہے۔ سے ایک منصوبہ ہے کہ اس میں مستقبل کے مختلف اخراجات کا نہ صرف ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے بلکہ ادارے کے اخراجات کو انہی فیصلوں کا پابند بھی کر دیا جاتا ہے۔(یادر ہے کہ بجٹ صرف مصارف بھی کے نہیں ہوتے بلکہ یہ آمدنی منافع خام مال پیداوار وغیرہ کے بھی ہو سکتے ہیں ) جب ہم کسی بجٹ کے لچکدار ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں اتنی گنجائش رکھی گئی ہے کہ بعض ایسی صورتوں میں جہاں وقت سے پہلے صیح اندازہ لگانا کسی قدر مشکل ہواوراسے دوسری مد میں بآسانی تبدیل کیا جاسکے۔ بعض بجٹوں میں اچھی خاصی رقوم اتفاقی یا غیر معمولی مصارف کیلئے پہلے سے تفویض کر دی جاتی ہیں۔ آئیے امداد باہمی کی ایک ایسی تنظیم میں بنائے گئے بجٹوں کا ذکر کریں سے تجارتی بنیادوں پر چلایا جارہا ہو اس تنظیم کا کل بجٹ دراصل کئی چھوٹے چھوٹے بجٹوں سے مل کر بنے گا۔
پیداواری بجٹ :
اس بحث میں مہینوں کے اعتبار سے مستقبل میں پیدا ہونے والی یا فروخت ہونے والی فصل کی مقدار کا ایک اندازہ شامل ہوتا ہے ۔ اس کی بنیاد پر ادارے کے ہدف (Target) مقرر کئے جاسکتے ہیں۔ اس بجٹ میں پہلے سے جمع شدہ فصلوں کی مقدار کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی بجٹ سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ کس فصل پر کب کام شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ نیز ان پر آنے والے اخراجات کتنے ہوں گے؟
خام مال کا بجٹ : پیداواری بجٹ میں لگائے گئے اندازوں کی بنیاد پر اس بجٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ادارے کو کس قدریج، کیمیائی کھاد اور کیٹرے مار ادویات مختلف مہینوں میں درکار ہوں گی ؟ اسی طرح اگر امداد با بی کی یہ تنظیم کچھ گھر یلو نعتیں بھی چلا رہی ہو تو ان صنعتوں کیلئے جس قدر خام مال درکار ہوگا اسے اسی بجٹ میں دکھایا جائے گا۔ اس طرح کے تفصیلی بجٹ نہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ کس قدر خام مال کے آرڈر کن کن تاریخوں کو دیئے جائیں گے بلکہ یہ بھی کہ مال کن کن تاریخوں کو وصول ہونا چاہیے؟ نیز یہ کہ ادارے کے پاس پہلے سے موجود خام مال کا کتنا اسٹاک ہے؟ اور کتنا اضافی مال خریدا جائے گا؟ قیمتوں کے متوقع اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے کس قدر لا گت آئے گی؟ وغیرہ وغیرہ۔
زرعی مشینری کی خرید اور اس کی دیکھ بھال کا بجٹ: اس بجٹ میں اوپر بیان کئے گئے دونوں بجٹوں کی بنیاد پر یہ اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ادارے کو مختلف وقتوں میں اپنے پیداواری ہدف کی تکمیل کیلئے کس قدر نئی مشینری خریدنا ہوگی یا کرائے پر لی جائے گی ؟ اس بجٹ میں پہلے سے موجود مشینوں اور ان نئی خریدی جانے والی مشینوں کی دیکھ بھال پر جو اخراجات ہوں گے انہیں بھی شامل کیا جاتا ہے۔
رقوم کی وصولی اور ادائیگی کا بجٹ :
اس بجٹ میں مختلف مہینوں کے اعتبار سے یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ادارے کو کتنا پیر مختلف ذرائع سے موصول ہوگا اور اس کتنی رقوم کی ادائیگی کرنی ہوگی ؟ پہلے سے اس قسم کے بجٹ کی تیاری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہےکہ ادارہ پیسوں کی کمی کی صورت میں خودکوپہلے سے تیار کرتا ہے اور ادارہ چلانے والوں کو پہلے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انہیں آنے والے مہینوں میں کس کس موقع پر کتنی رقوم درکار ہوں گی؟ منافع کا بجٹ: مستقبل میں فروخت ہونے والی فصل کی مقدار متوقع قیمتوں اور کل اخراجات کے تخمینوں کی بنیاد پر یہ بجٹ تیار کیا جاتا ہے۔
درج بالا چند مثالوں کے علاوہ کسی بھی ادارے میں اس طرح کے مزید بجٹ تیار کئے جاسکتے ہیں مثلاً ایک بجٹ ایسا ہو سکتا ہے جسے مختلف مراکز اور دیہی کونسلوں وغیرہ کی بنیاد پر تشکیل دیا ہوکسی بھی ادارے کے مقاصد کے حصول کیلئے یہ بجٹ نہایت ضروری ہیں اور ان سے ادارے کی سرگرمیوں کو صحیح سمت ملتی ہے۔ ان کی تیاری کے وقت ادارے کے فوری قلیل المیعاد اور طویل المیعاد مقاصد سامنے رہنے چاہئیں۔
پروگرام اور پراجیکٹ:
دوسرے عارضی منصوبوں کی مثال ادارے کے پروگرام اور پراجیکٹ ہیں۔ زرعی ترقی کے کسی بڑے منصوبے میں شامل کارکنوں
کی تربیت کا کوئی چھوٹا منصوبہ ایک پروگرام کی مثال ہے۔ اگر اس پروگرام کا مقصد زرعی کارکنوں کوموقع پر ہی عملی تربیت دینا ہے تو زرعی ماڈل فارموں کی تشکیل کا کام پراجیکٹس کے زمرے میں آئے گا۔ پروگرام اور پرا جیکٹ کی بہت ہی خصوصیات مشترک ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ مؤخر الذکر کی حیثیت پروگرام کے ایک جزو کی ہوتی ہے۔
منصوبوں کی اقسام:
یہ بات شاید کسی حد تک صحیح ہے کہ اعلی سطح پرفائزہ منتظمین اپنا زیادہ وقت منصوبہ میں صرف کرتے ہیں ۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مچلی سطحوں پر کام کرنے والے اپنے منصو بے ان منصوبوں سے اخذ کرتے ہیں جو اعلی سطحوں پر بنائے جاتے ہیں اس لئے مؤخر الذکر منصوبے کافی پہلے تیار کرنے پڑتے ہیں ۔ پس ظاہر ہے کہ کسی بھی اداری ڈھانچے میں کوئی شخص جتنا اونچا فائز ہوگا اتناہی اس کا واسطہ طویل المیعاد منصوبوں سے ہوگا ۔
کسی بھی ادارے میں مختلف سطحوں پر جو منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ انہیں ہم کئی طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں منصوبہ بندی کا آغاز ان مقاصد سے ہوتا ہے جو اس کے پیش نظر ہوں۔ انہی مقاصد سے کوئی ادارہ سب سے پہلے تو اپنے وہ منصو بے اخذ کرتا ہے جن کی نوعیت کسی قدر مستقل ہو۔ انہیں ایک دفعہ بنانے کے بعد بار بار استعمال میں لایا جاسکتا ہے اور انہیں ہم کسی ادارے میں راج پالیسیوں میں عمومی طریق کار اور قواعد وضوابط کا نام دیتے ہیں ۔ اس کے بعد ادارہ اپنے ایسے منصوبوں کو وجود میں لاتا ہے جن کی نوعیت کسی قدر عارضی ہو اور وہ وقتی مقاصد کے حصول کے بعد ہر بار نئے سرے سے تیار کئے۔ جاتے ہوں۔ ادارے کے مختلف پروگراموں پرا جیکٹوں اور بحیث وغیرہ کو ہم ان میں شامل کر سکتے ہیں:
پالیسیاں :
عموما ہمارے ہاں کسی ادارے میں رائج پالیسیوں اور عمومی طریق کار کی واضح تعریف نہیں کی جاتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات قواعد و ضوابط کو پالیسیوں کا نام دے دیا جاتا ہے یا عمومی طریق کاری کو پالیسی سمجھایا جاتا ہے ہا ان کے فرق کوسمجھنا بڑا ضروری ہے تا کہ منصوبہ بندی کے مختلف مراحل زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ کسی ادارے میں جاری کئے گئے ایسے عمومی بیانات جو فیصلہ سازی میں مددگار ثابت ہوں اس ادارے کی پالیسیاں کہلاتے ہیں ۔کسی پالیسی سے وہ حدود متعین ہوتی ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کئے جاسکتے ہیں مثلاً اگر کسی ادارے کا مقصد امداد با بی کی تنظیموں کا قیام ہے تو اس ادارے کا منتظم اعلیٰ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ کوشش کرے گا کہ ان مختلف طریقوں کی نشاندہی کرے جن سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہو ۔ ظاہر ہے اس مقصد کے حصول کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن فرض کیجئے پہلے طے یہ پاتا ہے کہ امداد باہمی کی ان تنظیموں میں صرف چھوٹے اور درمیانے درجے کے کا شتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ ایک پالیسی بیان ہوگا۔ اب اس پالیسی کے اندر رہتے ہوئے دیگر کئی فیصلے کئے جاسکتے ہیں ۔ دراصل مقاصد سے پالیسیوں کی تشکیل اور پھر پالیسیوں سے عمومی طریق کار کا تعین اور پھر عمومی طریق سے قواعد وضوابط بنانے کا کام بتدریج فیصلہ سازی کے عمل کو محدود سے محدودتر کرتا چلا جاتا ہے۔ جہاں پالیسیاں عمومی بیانات ہوتے ہیں قواعد وضوابط کی نوعیت خصوصی ہوتی ہے۔ مؤخر الذکر وہ خصوصی احکامات ہوا کرتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یایہ کہ کیا صیح ہے اور کیا غلط؟ پس کوئی بھی ادارہ سب سے پہلے اپنے فوری قلیل المیعاد اور طویل المیعاد مقاصد کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ان مختلف مقاصد کے حصول کیلئے ہر شعبے میں پالیسیاں بھی وضع کی جاتی ہیں ۔ مثال کے طور پر کسی امداد باہمی کے ادارے میں یہ پالیسیاں زرعی . لوازمات پیج کھاؤ کیڑے مار ادویات کی خرید اجناس کی فروخت سرمائے کی فراہمی ممبران کی شمولیت ادارے کے انتظام چلانے کیلئے کارکنوں کی بھرتی اور پیسے کے عام لین دین یا ادارے کے حساب کتاب رکھنے کے بارے میں ہو سکتی ہیں ۔ اس طرح یہ پالیسیاں ہر معالقہ شعبے میں نہ صف ادارے کی سرگرمیوں کو ایک : 3 واضح سمت دینے کا ایک اہم کردار ادا کریں گی بلکہ قدم قدم پر مختلف فیصلوں کے معاون اصول بھی یہی پالیسیاں ہوں گی مثلا فرض کیجئے اگر یہ پالیسی ادارے میں ملازمین کی بھرتی کے بارے میں ہے تو پھر ہمیں مناسب افراد کے انتخاب ان کی تربیت ان کی کارکردگی او معاوضے وغیرہ کے بارے میں رہنما اصول اسی پالیسی میں ملنے چاہئیں۔
عموی طریق کار :
کسی بھی ادارے میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بارد ہرایا جاتا ہے جس سے ادارے کا روز روز کا واسطہ ہوتا ہے مثال اگر یہ ایک ایسا دفتر ہے جس میں خاص قسم کی درخواستیں وصول کی جاتی ہوں تو ادارہ چاہے گا کہ یہ درخواستیں وصول کرنے اور ان سے مؤثر طریق پر پیٹنے کیلئے کوئی عمومی طریق کا روضع کرے مثلا یہ طریقہ اختیارکیا جا سکتا ہے کہ یہ درخواستیں ایک خاص فارم پر دی جائیں اور انہیں کسی خاص جگہ داخل کرایا جائے وغیر وغیرہ ۔ در اصل جب کوئی ادارہ اپنے اس قسم کے روزمرہ کے کاموں میں کسی قدر ضبط پیدا کرنے کا خواہشمند ہو تو اس طرح کے عمومی طریق کار کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ادارے کا یہ فیصلہ کہ صرف چھوٹے اور درمیانے درجے کے کا شتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر ایک پالیسی کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر اس سے مطابقت رکھتا ہوا ایک عمومی طریق کا رہو اس مرحلے کے بارے میں ہوگا جو اس پالیسی کے اپنائے جانے کی صورت میں اختیار کیا جائے گا۔ اس طریقہ کی ایک مثال درخواست کیلئے بھرے گئے فارم پر ان ہدایات کی شکل میں ہو سکتی ہے جس میں درخواست دہندہ سے کہا جائے کہ وہ مالی حالت سے متعلقہ کو الف کس طرح درج کرے عمومی طریق کار کی دوسری مثال ہم ایک ایسی ہوائی کمپنی سے دے سکتے ہیں جس میں یہ پالیسی اختیاری جائے کہ وہ ہوائی جہازوں کی دیکھ بھال کے حفاظتی انتظامات پر زیادہ زور دے گی ۔ ظاہر ہے اس کیلئے یہ عمومی طریق کار واضح کرنا ہوگا کہ کسی خاص پرزے کو جانچتے وقت پہلے کیا چیز دیکھی جائے اور پھر اس کے بعد کون سی اور پھر کس طرح باری باری اس پرزے کے کسی حصے کو دیکھنے کے بعد دیگر حصوں سے ہوتے ہوئے اس حصے تک پہنچا جائے جو اکثر خراب ہو جاتا ہے۔
(ب) بنیادی معاشرتی تصورات
جواب: معاشرتی تصورات:
آج ہماری دنیا انسانوں سے بھری پڑی ہے۔ اس ساری زمین پر اگر صرف ایک فرد تہائی میں زندگی بسر کرتا تو اس کی زندگی ہم سے یقیناً مختلف ہوتی۔ وہ کیا کرتا اور اس کے دن اور رات کس طرح گزرتے ؟ شاید اس کا تصور ہم مشکل سے کر سکیں لیکن اگر کوئی یہی سوال ہم سے اس طرح پوچھے کہ یانہ کرتا تو اس شخص کی کہانی لکتے وقت ہ کم ازکم یہ باتیں برے یقین کے ساتھ کہ سکتے ہیںوہ کوئی زبان نہ بول سکا کیونکہ نہ میں تو نے ہی جیسے انسانوں سے بولی جاتی ہیں۔ وہ اپنے ہی جسے کسی انسان کیلئے محبت نفرت حسد اور جلن جیسے احساسات سے آزاد ہوتا۔ اسکا کوئی خاندان برادر اور قبلہ نہ ہوتا کیونکہ خاندان برادری اور قبیلے تو لوگوں سے مل کر بنتے ہیں ۔ اس کا کوئی پیشہ نہ ہوتا کیونکہ پیٹوں کی تقسیم تو تب ہوتی ہے جب کچھ لوگ مل کر ایک خاص قسم کا کام کاج اپنا ئیں ۔ اس کے ہاں کسی قسم کے رسم و رواج نہ ہوتے کیونکہ یہ تو ان مروجہ طریقوں کا نام ہے جن کے ذریعے لوگ اپنی خوشیوں اور اپنے غموں کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سڑکوں پر چلتے ہوئے جلوسوں میں شریک نہ ہوتا کیونکہ وہاں نہ تو سڑکیں تھیں اور نہ جلوس۔ وہ کہیں ملازم نہ ہوتا اور نہ ہی اس کا کسی سے کسی قسم کا لین دین ہوتا۔ وہ قانون کا پابند نہ ہوتا کیونکہ قانون تو اس لئے بنتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ اس پر نہ تو کسی قسم کے فرائض عائد ہوتے اور ندہی وہ کسی قسم کے حقوق رکھتا کیونکہ حقوق وفرائض کا ذکر تو تب ہوتا ہے جب کوئی شخص کہے کہ یہ چیز میری ہے اور دوسرا کہے یہ تمہاری نہیں میری ہے ۔ وہ کسی 3 ملک کا باشندہ نہ ہوتا کیونکہ ریاست اور ملک تو افراد سے مل کر بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے ایسے فرد کی کہانی اگر اس طرح لکھی جائے تو یہ کبھی ختم نہ ہو سکے گی اور . شاید ہم اسے صرف یہ کہ کر ختم کر سکیں کہ ایسے انسان کی تو کوئی کہانی ہ نہ تھی کیونکہ کہانیاں بھی تو دوسروں کیلئے لکھی جاتی ہیں ۔“ اب فرض کیجئے ایک اور انسان کہیں سے اچانک نمودار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اب صورتحال بالکل بدل جائے گی ۔ پیچھے لکھے گئے کئی ” نہ اب اچانک : 3 غائب ہو جاتے ہیں اور ایسی کئی باتیں جنہیں ہم پہلے تصور بھی نہ کر سکتے تھے اب ایک حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں۔ کسی زبان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ محبت نفرت حسد اور جلن جیسے احساسات کا ذکر اب بے معنی نہیں۔ کسی کہانی کا ذکر بھی بڑا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حقوق و فرائض کا تصور بھی جنم لیتا ہے اور شاید خاندان برادری اور قبیلے کا سلسلہ بھی چل نکلتا ہے پھر جوں جوں افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کئی ایسی باتیں مثال پیشہ ملازمت لین دین رسم ورواج ، جلسے جلوس ریاست اور مملکت وغیرہ جنہیں پہلے ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا تھا اب ان کی تصویر میں ہمارے ذہنوں میں کسی نہ کسی شکل میں اچانک ابھرتی ہیں مثال ایک ایسے شخص کا تصور کرنے کے بعد جو اسارے کرہ ارض پرتارہورہاتھا ہم انھیں بندکرکے اسکے گرد پھر بالا نگ اور ہے دریا تو یہ کتے میں کی کمی کمک کرم و رواج کا تصور نہیں کر سکتے لیکن اب ہمارے ذہن کے پردے پر رسم و رواج کی کوئی نہ کوئی شکل بتدریج ضرور بھرتی ہے اور آخر کا ر تصور میں ہم شادیوں میں دلہن کے ہاتھوں کو مہندی لگتے اور سارے گھر کو جھنڈیوں سے سجا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہمیں ڈھول کی تھاپ پر سکھیوں کے گانوں کی نہ صرف آواز سنائی دیتی ہے بلکہ دیگ میں پکے ہوئے چاولوں کی خوشبو کا بھی احساس ہونے لگتا ہے۔ جب ہم پیشوں کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن کی آنکھ اپنے ملک کے ہزاروں کہ سانوں، مزدوروں ر کھانوں حجاموں ڈاکٹروں دائیں دوکانداروں اور یوں ارکان کنوں کے پہرے آسانی سےدیکھ سکتی ہے۔ جب ہمارے کان لفظ ملازم سنتے ہی تو ہمارے ذہن کے پردے پر نہ جانے کتنی تصویر یں ایک دوسرے کے بعد ابھرتی ہیں۔ صبح صبح بس سٹاپ پر کھڑے ملازم پیشہ حضرات دفاتر کی عمارتیں، کمروں کے ل باہر دروازوں پر ناموں کی تختیاں میزیں کرسیاں اور فائلوں کے ڈھیٹر دفتری اور کرک وغیرہ ۔ جب بات لین دین کی ہوتی ہے تو شاید ہماری اندرونی آنکھ جہاں کو ایک بوڑھے کسان کو اپنی جوتی کے پو میں سے دس دس کے نہ جانے کتنے نوٹ بڑی احتیاط سے کال کر گتے ہوئے دیکھتی ہےوہاں ہمیں بینکوں پرلوگوں کی بھی لمبی قطاریں بھی نظر آتی ہیں۔ بازاروں میں ہزاروں افراد طرح طرح کی چیزیں خریدتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماراز بن اس شدت سے تصویر کشی کرتاہے کہ ہمیں بھرے بازاروں میں موٹروں کے ہارن اور ریڑھی والوں کی آواز میں تک سنائی دینے لگتی ہیں۔ بازار میں کسی گنڈ میری بیچنے والے کی آوازیں یقینا دوسروں ہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے ہوا کرتی ہیں ۔ ہمارے لئے یہ تصور کرنا کہ ایک شخص جو اس ساری زمین پر تنہا زندگی بسر کر رہا ہو۔ خوانچہ لگانے اور آوازیں لگاتا پھرے بڑا مشکل کام ہے ۔ ہم جب جلسہ جلوس کا نقشہ اپنے ذہن میں کھنچتے ہیں تو شاید پلے کارڈز لوگ نعرے تقریریں اکھیاں آنسو گیس اور لیڈ راس تصویر کا جزو بنتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہےکہ ہر تصویر اپنے اندر کی اور تصاویر لئے ہوتی ہے مثالا جب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں تو سپاہی سے لے کر عدالتیں، قانون گو پولیس کی گاڑیاں نیشنل اسمبلی جھیلیں، چالان عضمانت، وکیل، سزا بھائی اور نہ جانے ایسےہی کتنے نقشے ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں ۔ اب انبی میں سے کسی ایک کے متعلق سوچیں تو کئی اور شکلیں جنم لیتی ہیں۔ جیلوں کا سوچیں تو ہتھکڑیاں سلاخیں، تنگ کو ٹھڑیاں، دیواریں قیدی اور پھر ان قیدیوں کے گھروں میں ان کی منتظر بیویاں اور بچے پٹواری کا سوچتے ہیں تو شاید ہمیں اس تصویر میں اپنے کھیت ان کی حد بندیاں پانی کی تقسیم کسانوں کے جھگڑے اور نہ جانے کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ کسانوں کے جھگڑوں پر غور کریں تو پھر سے عدالت چالان ضمانت وکیل وغیرہ کی تصویر میں ہمارے ذہن میں ابھرتی ہیں۔ غرضیکہ ان تصاویر کاایک نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے کہ ہم چاہیں تو صفحوں پر صفحے بھرتے چلے جائیں۔
ان تصاویر کو جو ہمارے ذہن میں ابھرتی ہیں ہم انگریزی زبان میں (Concepts) کہتے ہیں جو دوسرے انگریزی لفظ (Conceive) سے نکلا ہے۔جس کے اردو کے معنی ہیں تصور کرتا“۔
فہرست پر ایک نظر ڈالے کے بعدہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کا نقشہ ہمارے ذہن میں ایک سے زیادہ افراد کی موجودگی اور ان کے باہمی تعلق کی نسبت سے پیدا ہوا۔ جہاں تک ان تین تصورات کا تعلق ہے جن کے نیچے ہم نے لائنیں کھینچ دی ہیں، آپ کو یاد ہو گا ان کا ذکر ہم نے کچھ یوں کیا تھا۔ یہ فرض کرنے کے بعد کہ ایک شخص اس ساری زمین پر کیا ہی زندگی بسر کر رہاہے۔ ہم آنکھیں بندکر کے اس کے گرد پھر پہاڑا جنگ اور بتے دریا تو دیکھ سکتے ہیں کسی کی ستم کے رسم و رواج کا تصور نہیں کر سکتے ۔“ یقینا یہاں ہم نے پتھر پہاڑ جنگل اور پتے دریا کو ایک سے زیادہ افراد کی موجودگی اور انکے درمیان کسی قسم کے با ہی تعلق کی نسبت سے نہیں سوچا۔ ہم نے اوپر دو قسم کے تصورات کا ذکر کیا۔ پہلے وہ جو ہمارے ذہن میں ایک سے زیادہ افراد کے باہمی تعلق کی نسبت سے پیدا ہوئے۔ دوسرے وہ جو ہمارے ذہن میں ایک سے زیادہ افراد کے باہمی تعلق کی نسبت سے پیدا نہیں ہوئے۔ پہلی قسم کے تصورات جو ہمارے ذہن میں ایک سے زیادہ افراد کے باہمی تعلق کے باعث پیدا ہوتے ہیں ہم انہیں معاشرتی تصورات Social Conceptsکہتے ہیں۔ معاشرتی حقائق کی بنیاد یہی معاشرتی تصورات بنتے ہیں۔

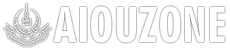









0 Comments